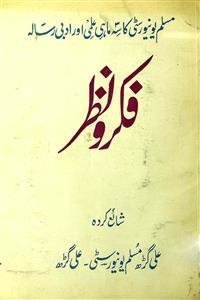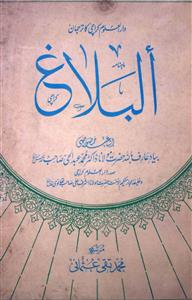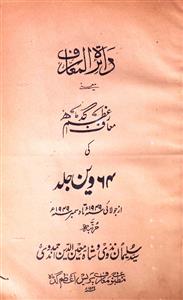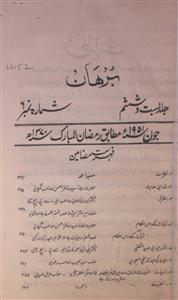" آج دنیا کے پاس وسائل کی کمی نہیں اگر کمی ہے تو اخلاق اور مقاصد زندگی کی ، یہ صرف انبیاء کرام اور آسمانی کتب میں ہیں ۔ آج دنیا کی تعمیر نو صرف اس طرح ممکن ہے کہ جو وسائل و زرائع جدید دور میں انسانوں نے پیدا کرلیے ان کی مدد سے اور انبیاء اور آسمانی کتب میں موجود انسانیت کے اخلاق اور مقاصد زندگی کی مدد سے دنیا کی تعمیر نو کی جائے ۔" (مفکر اسلام سید ابوالحسن علی ندوی ؒ )
جب انڈیا نے خوراک کے بحران سے نمٹنے کے لیے امریکی کتب خانوں کا سہارا لیا
جشن ریختہ کیا ہے ؟
ریختہ کیا ہے؟
ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم کی کتابیں
نامور فلسفی محقق ماہر اقبالیات ،مترجم اور افکار غالب ، حکمت رومی، تشبیہات رومی، فکر اقبال اور داستان دانش جیسی کتابوں کے خالق
افکار غالب
1954
علامہ اقبال
داستان دانش
1943
فکر اقبال
1988
فکر اقبال
1992
فکراقبال
1968
الفت بے اثر کو کیا کہئے - کلامِ شاعر بزبانِ شاعر مرزا حامد لکھنوی
مرزا حامد لکھنوی
اسلوب تحریر کیا ہے؟
ابو فہد ندوی
اسلوب تحریر ہر صاحب قلم کے لکھنے کے اپنے اسٹائل کا نام ہے۔ اسلوب تحریر صاحب قلم کے مخصوص لفظیات، پھر انھیں خاص طرز پر ترتیب دینے کے ذاتی ہنر اور استعداد اور پھر استعاروں اور ضرب الامثال وغیرہ کو اس کے اپنے خاص طرز پر برتنے سے تشکیل پاتا ہے۔ یہ سرتا سر کوئی ذہنی رویہ یا فکرو رجحان نہیں ہے، البتہ یہ صاحب قلم کے ذہنی رویوں کا غماز اور فکر ورجحان کا پرتو ضرور ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسلوب تحریر صاحب قلم کے اسلوب زندگی کا پرتو ہے۔
اگر قلم کار کا ذہن صاف اور شارپ ہے تو اسلوب بھی صاف اور شارپ ہوگا اور اگر ذہن صاف نہیں ہے اور فکر گنجلک ہے تو اس کا اسلوب بھی گنجلک، بے معنیٰ اور تضادات سے بھرا ہوا ہوگا۔ کیونکہ صاحب قلم اگر کسی مسئلے یا کسی فکر کو بذات خود نہیں سمجھ سکتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نہیں سمجھا سکتا، قلم کے ذریعے بھی نہیں، کم از کم مکمل وضاحت کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ اسلوب کا تعلق جس قدر فصاحت وبلاغت کی اضافی اور مقتدر صلاحیتوں سے ہے اسی طرح اس کا تعلق ذہنی رویوں اور ذہن میں پرورش پانے والے افکار سے بھی ہے۔
قلم کار اپنی کسی تحریر میں جو کچھ پیش کر رہا ہے، جس فن پر یا موضوع پر خامہ فرسائی کر رہا ہے اگر وہ اس کے تعلق سے بہت زیادہ مطمئن ہے اور اس کے تمام ابعاد اور تمام مہمات اس کے ذہن میں روشن ہیں بلکہ اس حد تک روشن ہیں کہ وہ خود اپنا بے تابانہ اظہار چاہتے ہیں اور اظہار کے لیے کسی پیرائے کے متلاشی ہیں تو قلم کار یا مصور اس کو بہت ہی آسانی اور حسن کارکردگی کے ساتھ اظہار کا جامہ پہنا سکتا ہے۔
آغا حشر کی کردار نگاری: ایک جائزہ
ڈاکٹر محمدشہنواز عالم
اسسٹنٹ پروفیسرشعبۂ اردو، اسلام پور کالج ، اتر دیناج پور، مغربی بنگال
یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے اس کی قدر دانی کے بجائے جو نہیں ہے اس کا رونا دھونا، اس کے نا ہونے پر پچھتانا اور ہاتھوں کا ملنا ہمارا معمول ہوتا ہے، یہ بات حسیاتِ انسانی کے لئے جتنی درست اور معنی خیز ہے اتنی ہی دنیائے ادب کے لئے بھی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معاملہ چاہے ادب کی تخلیق کا ہویا تنقید کا، ہر جگہ ہمیں احساسِ محرومی اور ناقدری کے نمونے مل جاتے ہیں۔ گو یہ کہ آغا حشر کے قلم کاروں کا عمل بھی اس سے مستثنیٰ نہیں رہا ہے۔ یعنی آغا حشر کے متعلق صرف یہ کہہ دینا کہ آغا حشر کے ڈرامے شیکسپیئر کے ڈرامے جیسے، سماجی شعور نظیر اکبر آبادی جیسا، فلسفۂ حیات اقبال جیسا اور زندگی منٹو کے کرداروں جیسی ہے جو بالکل درست نہیں ہے کیوں کہ آغا حشر کا سب کچھ ان کے جیسا تھا۔ ان کی تمام خوبیاں، خامیاں اور ان کی زندگی کا ایک ایک عمل ان کا اپنا ہے چنانچہ ہم اس بات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو ان کے ڈرامے شیکسپیئر کے ڈراموں کے متبادل ہوسکتے ہیں، نا ان کی شخصیت منٹو کے کردارجیسی ہے، نہ ان کا فلسفۂ حیات اقبالؔ کے فلسفۂ حیات جیساہے اور نہ ہی آغا حشر کا سماجی شعور نظیر سے کوئی مطابقت رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ آغا حشر نے اپنے عہد کے تلخ حقائق اور شیرین آواز کو اپنے فن کے قالب میں ڈھال کر اسے ڈراموں کا جامہ پہنا کر دنیا والوں کے سامنے تا عمر پیش کرتے رہے۔ اور یہ وہی سچائی ہے جو انہیں اپنے ہم عصروں میں قد آور اور ممتاز کرتی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر محمد شاہد حسین رقمطراز ہیں۔
’’احسن و بیتاب کے ہم عصروں میں ڈرامے کی دنیا کا ایک بہت ہی اہم اور معروف نام آغا حشر کا ہے ہمارے ڈرامے کی تقریباً سوا سو برس کی تاریخ میں عوام اور خواص دونوں میں امانت کے بعد جو مقبولیت آغا حشر کے حصہ میں آئی اس سے دوسرے ڈراما نگار محروم ہیں۔
آغا حشر احسنؔ و بیتابؔ کے ہم عصر ضرور ہیں مگرا نہوں نے ڈراما نگاری اس وقت شروع کی جب احسنؔ و بیتابؔ اپنا عروج حاصل کرچکے تھے۔ اور ان کی عظمت و اہمیت تسلیم کی جا چکی تھی، مگر آغا حشر نے ڈراما نگاری اس شان سے شروع کی کہ اپنے ہم عصروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔‘‘ ۱؎
بیانیہ :تعریف و توضیح
ریاض احمد کٹھو
ریسرچ اسکالر،شعبۂ اردو،کشمیر یونی ورسٹی،سری نگر ،کشمیر۱۹۰۰۰۶
بیانیہ کاجہاں تک تعلق ہے اردو کی مشہور تنقید نگار ممتاز شیریں اپنے مضمون’’تکنیک کا تنوع۔ناول او رافسانے میں ‘‘ میں لکھتی ہیں
’’بیانہ صحیح معنوں میں کئی واقعات کی ایک داستان ہوتی ہے جو یکے بعد دیگرے علی الترتیب بیان ہوتے ہیں‘‘ ۱
ممتاز شیریں کے اس قول سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ بیانیہ دراصل کسی تحریر یا فن پارے میں کوئی واقعہ یا مختلف واقعات کی ایک ترتیب ہوتی ہے جو یکے بعد دیگرے تہہ در تہہ کھلتے ہیں۔بیانیہ اسلوب میں مصنف کسی واقعہ‘ قصہ‘ مطالعہ یا مشاہدے کو حکایتی یا کہانی کے انداز میں پیش کرتاہے ۔بیانیہ میں کوئی بھی تجربہ جائز ہے ۔ بیانیہ میں مصنف کوئی واقعہ یا قصہ کرداروں‘مکالموں یا مختلف مناظر کے ذریعے پیش کرسکتا ہے یا پھر وہ کسی فن پارے میں بیانیہ کاپیرائیہ تیار کرنے کے لیے داخلی خود کلامیInternal Monologueکاسہارا بھی لے سکتا ہے ۔اگر بیانیہ ایک طرف اکہرا‘رومانوی یا حقیقت پسندانہ ہوسکتاہے تو دوسری طرف اس میں علامت او رتجرد کااستعمال بھی جائز ٹھہرتا ہے ۔بیانیہ سے فکشن کاپورا تانا بانا تیار ہوتاہے جس کے لیے کہانی ایک جُز یا حصے کی حیثیت رکھتی ہے جو بمعنیStory Lineکے بیانیہ میں جاری رہتی ہے اور آگے بڑھتی رہتی ہے اس سے کسی فن پارے یا تحریر کاپلاٹ تیار ہوتاہے اور یہ Story Lineفکشن میں کرداروں یاواقعات یا مکالموں یا مختلف مناظر کو تشکیل دیتی ہے اور یہ سب چیزیں مل کربیانیہ کی شکل متعین کرتی ہیں۔
بیانیہ کاایک سرا جہاں متھ(Myth) اساطیر‘ تمثیل ‘ حکایت‘ دیو مالا‘ کتھا کہانی وغیرہ جیسی قدیم لوک روایتوں سے ملتاہے تو دوسرا سرا ڈرامہ‘ ناول‘ افسانہ جیسی جدید اصناف سے ملتاہے ۔بیانیہ میں صنفی ‘موضوعاتی یا ہیئتی اعتبار سے کوئی قید نہیں ہے ۔بیانیہ کو واقعہ یا قصہ سے غرض ہے ۔مشہور نقاد و محقق شمس الرحمن فاروقی لکھتے ہیں:
’’بیانیہ سے مراد ہر و ہ تحریر ہے جس میں کوئی واقعہ یا واقعات بیان کئے جائیں‘‘ ۲
تاہم بیانیہ میں وقت کی قید ضرور ہے اور ہر بیانیہ وقت کا پابند ہوتاہے بقول شمس الرحمن فاروقی:
’’بیانیہ کا وجود ہی وقت پر منحصر ہے‘‘ ۳
گوپی چند نارنگ بیانیہ کے لیے وقت کی قید کو ضروری سمجھتے ہیں۔ان کے نزدیک بیانیہ کے لیے ضرور ی ہے کہ وہ ماضی سے تعلق رکھتا ہو۔نارنگ لکھتے ہیں:
’’ حال اور مستقبل میں Imperfectiveیعنی پیرایہ دیکھنے والی نظموں( شاعری) میں زیادہ تر بیانیہ نہیں فقط بیان ہوتا ہے ‘ یا پھر یہ منظر یہ ہوتی ہیں‘‘ ۴
دار الافتاء ڈاٹ انفو۔۔ مختصر تعارف
دار الافتاء دار العلوم دیوبند
دار الافتاء دار العلوم (وقف) دیوبند
دار الافتاء دار العلوم کراچی
دار الافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیۃ بنوری ٹاؤن
دار الافتاء اشرف المدارس کراچی
دار الافتاء خیر المدارس ملتان
دار الافتاء جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک
دارالافتاء جامعہ دارالعلوم یاسین القرآن کراچی
دار الافتاء صادق آباد
دار الافتاء جامعہ فاروقیہ
دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی
دار الافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور
دار الافتاء جامعہ بنوریہ کراچی
دار الافتاء الاخلاص کراچی
دار الافتاء جامعہ عثمانیہ پشاور
عرب دنیا کی عربی زبان و ادب کی سرکاری اکیڈمیوں کا تعارف
مجمع اللغة العربية - قاھرہ
مجمع اللغۃ العربیۃ 14 شعبان 1351 ھ، بمطابق 13 دسمبر 1932ء مصر کے بادشاہ فواد اول کے عہد حکومت میں قائم ہوا۔ اس میں بقاعدہ کام 1934ء سے شروع ہوا۔
اس کے کل ممبران 20 ہیں، 10 مصری ہوتے ہیں اور 10 عرب اور غیر عرب۔ ارکان کے لیے کسی مذہبی پس منظر رکھنے کی ضرورت نہیں صرف علمی اور لسانی مہارت ہی بنیادی شرط ہے ۔
پچھلے نصف صدی میں درج ذیل شخصیات نے اس کی صدارت کی ہے:
1- محمد توفيق رفعت (1934 - 1944)2- أحمد لطفي السيد (1945 -1963)4- الدكتور إبراهيم مدكور (1974 - 1995)5- الدكتور شوقي ضيف (1996 -2005)6- الدكتور محمود حافظ (2005 -2011)7- الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي فروری 2012م سے رئیس ہیں۔
مجمع مین بطور نائب رئیس خدمات انجام دینے والوں کے اسمائے گرامی :
الأستاذ الدكتور طه حسين
الأستاذ زكى المهندس
الأستاذ الدكتور أحمد عمار
الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام
الأستاذ الدكتور شوقى ضيف
الأستاذ الدكتور محمود حافظ
انڈیا میں اردو کے فروغ کی کوششوں کا جائزہ
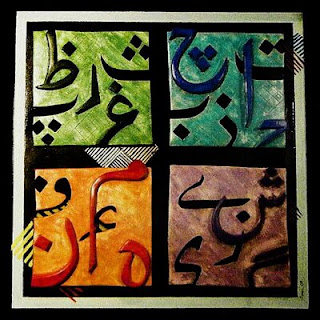 |
| انڈیا میں اردو کے فروغ کی کوششوں کائزہ |
اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا میں عام طور پراردو کو مسلمانوں اور اسلام کی زبان سمجھاجاتا ہے، اس لئے اردو کو اسلام اور مسلمانوں سے جوڑا جاتا ہے۔
تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے اردو کے جتنے ادبی جلسے منعقد ہوتے اس کی سربراہی کوئی نہ کوئی مسلمان ادیب یا شاعر کرتے تھے ۔ لیکن اب معاملہ اس کے برعکس ہے ۔
اگر صرف دلی کا ذکر کیا جائے تو یہاں اردو کے بہت سے پروگرامز ادبی کلینڈر کا حصہ ہیں، لیکن یہاں جوبھی بڑے ادبی جلسے اورجشن منائے جاتے ہیں سب کی سربراہی غیر مسلموں کے پاس ہے، جیسے :
- شنکر شاد مشاعرہ
یہ دو اہم ہندو شاعروں شنکر لال شنکر اور لالہ مرلی دھر شاد کی یاد میں منایا جاتا ہے اور اسے ایک بڑی کمپنی ڈی سی ایم سپانسر کرتی ہے۔
- مشاعرہ جشن بہار
اس کی روح رواں بھی ایک ہندو عورت کامنا پرساد ہیں۔
- جشن ریختہ
اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں اردو کے فروغ میں اس نئی مقبولیت کا سہرا ریختہ ڈاٹ او آر جی کے سرجاتاہے، جس کے بانی معروف شخصیت سنجیو صراف ہیں ۔ اس سے اردو کی مقبولیت کو ایک نیا پلیٹ فارف فراہم ہوگیا ہے۔
المعجم الكبير- مجمع اللغة العربية - القاهرة ، فری ڈاؤن لوڈ کریں
 |
| المعجم الكبير مجمع اللغة العربية - القاهرة |
مجمع اللغۃ العربیۃ قاھرہ کا یہ سب سے بڑا پراجیکٹ ہے ۔ پہلے اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس کو انگریزی زبان کی سب سے بڑی " آکسفورڈ ڈکشنری" کے طرز تیار کیا جائے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی پالیسی میں تبدیلى آتى گئ ۔
1970 سے 2022ء تک اس کی کل 8 جلدیں شائع ہوچکی ہیں۔- اب تک صرف حرف (ا) سے حرف (ص) تک کے الفاظ پر کام مکمل ہوا ہے۔ جو تقریبا بندرہ حصوں پر مستمل ہیں ۔ پندرہویں حصہ کا پہلا ایڈیشن، حرف (ص ) کے لیے مختص ہے ، جو جون 2022 میں شائع ہوا۔
اس کے لیے لسانیات اور لغت کے ماہرین کی ایک خصوصی کمیٹی مختص ہے ان کی نگرانی میں مندرجہ ذیل خصوصیات کے ساتھ کام جاری ہے :
اس میں عربی لسانیات کے بارے میں مکمل معلومات ہیں جیسے زبان، ادب، علم الصرف، وعلم النحو، علم البلاغۃ اور اسی طرح تاریخ، جغرافیہ، نفسیات، فلسفہ، انسانی علوم، معاشرتی علوم ، تہذیب، اور تمدن کے بارے میں تمام اصطلاحات شامل ہیں، اس کے ساتھ جدید سائنسی اور تکنیکی اور تحقیقاتی اصطلاحات بھی شامل ہیں۔
درج ذیل لنک سے فری ڈاؤن لوڈ کریں !
المعجم الكبير المجلد الأول
مولانا امتیاز علی عرشی کی تصنیفات
 |
| مولانا امتیاز علی عرشی خان کی تصنیفات |
مولانا متیاز علی عرشی 8 دسمبر 1904ء کو رام پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد میں حاجی خلیل، قبائل (سوات) کے سردار تھے۔ جب ہجرت کرکے ہندوستان آئے تو رامپور کے آس پاس کے علاقوں پر قابض ہو گئے جو بعد میں نواب فیض اللہ خان کو سونپ دیے۔ مولانا کے والد وٹنری ڈاکٹر تھے جو ریاست رام پور کے ہسپتال کے انچارج تھے۔
تعلیم کے بعد بہت سے کاموں سے وابستہ رہے ، آخر سب سے سبکدوش ہوکر رامپور کے ایک عظیم ادارے رضا لائبریری سے وابستہ ہوگئے جہاں نادر و نایاب کتابوں کا ایک ذخیرہ اب بھی موجود ہے۔ اسی ذخیرے سے وہ خود فیض یاب ہوئے اور علمی دنیا کو اس سے فیض پہنچایا۔ ان کا اصل میدان عربی ادب تھا لیکن اردو میں بھی ان کے کارنامہ نہایت اہم ہیں۔
مولانا نے عربی فارسی اور اردو تینوں زبانوں میں تنقید و تحقیق کے ایسے موتی سجائے جن کی مثالیں صرف متقدمین کے یہاں ملتی ہیں ۔
قرآنیات اسلامیات اور عربی ادبیات میں عرشی صاحب کی بہت سی دریافت اضافہ ہیں ، آپ کی اسی علمی وقار کی بناء پر آپ کو عربی " نیشنل اسکالر " قرار دیا گیا ہے ۔ عرب اور یورپی ممالک میں آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا گیا ہے ۔ آپ کے تحقیقی کاموں ميں سب سے نمایا کا م مستشرقین کی غلطیوں پر گرفت ہے۔
وہ تحقیق کے آخری پتھر کو چھولینے لے لئے سردھٹر کی بازی لگادیتے جس کی مثال تفسیر سفیان ثوری پر آپ کے حواشی اور تعلیقات ہے۔عرشی صاحب کی کاوش سے تفسیری لٹریچر میں ایک نیا اضافہ ہوا ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیری دنیا میں اس تفسیر کی اشاعت سے نئی تاریخ رقم ہوئی ۔ کیونکہ تاریخ تفسیر میں تفسیر ابن جریر سے قبل کسی مرتب تفسیر کا پتہ نہیں تھا ۔ مولانا نے اس تفسیر کو جس محنت اور ریاضت سے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ ایک مثال بن گئی ۔
اسی طرح آپ کا دوسرا کام " شواہد القرآن للطبری " ہے۔ طبری نے مفردات القرآن کی تفسیر اور توضیح کے لئے کلام عرب سے استدلال اور استشہاد کیا ہے ان عربی اشعار کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے عرشی صاحب نے ان کی تحقیق و تخریج میں نہ جانے کتنے ہفت خان طے کئے۔
اس کے علاوہ آ پ کا ایک قابل قدر کام رضا لائبریری رام پور کے عربی اور اردو کے مخطوطات کی فہرست سازی ہے اس کا ایک بڑا حصہ قرآنیات سے بھی متعلق ہے۔
مولانا اسلم جیراجپوری کی تصنیفات
 |
| مولانا اسلم جیراجپوری کی تصنیفات |