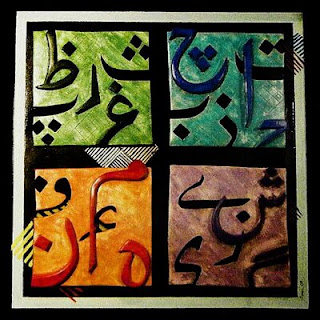|
مسلمانوں کے لیے
جدید تعلیمی پالیسی
اور لائحہ عمل |
یہ وہ نوٹ ہے جو مسلم یونی ورسٹی علی گڑھ کی مجلسِ اصلاحِ نصابِ دینیات کے استفسارات کے جواب میں بھیجا گیا تھا۔ اگرچہ اس میں خطاب بظاہر مسلم یونی ورسٹی علی گڑھ سے ہے‘ لیکن دراصل اس کے مخاطب مسلمانوں کے تمام تعلیمی ادارات ہیں۔ جس تعلیمی پالیسی کی توضیح اس نوٹ میں کی گئی ہے‘ اسے اختیار کرنا مسلمانوں کے لیے ناگزیر ہے۔ علی گڑھ ہو یا دیوبند یا ندوہ یا جامعہ ملیہ‘ سب کا طریقۂ کار اب زائد المیعاد ہوچکا ہے‘ اگر یہ اس پر نظرثانی نہ کریں گے تو اپنی افادیت بالکل کھودیں گے۔
مسلم یونی ورسٹی کورٹ اس امر پر تمام مسلمانوں کے شکریے کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے ادارے کے بنیادی مقصدیعنی طلبہ میں حقیقی اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کی طرف توجہ کی، اور اس کو روبعمل لانے کے لیے آپ کی مجلس کاتقرر کیا۔ اس سلسلے میں جو کاغذات یونی ورسٹی کے دفتر سے بھیجے گئے ہیں ان کو میں نے پورے غور و خوض کے ساتھ دیکھا۔ جہاں تک دینیات اورعلوم اسلامیہ کے موجودہ طریق تعلیم کا تعلق ہے اس کے ناقابل اطمینان ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جو نصاب اس وقت پڑھایا جا رہا ہے وہ یقیناًناقص ہے، لیکن مجلس کے معزز ارکان کی جانب سے جو سوالات مرتب کیے گئے ہیں‘ ان کے مطالعے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجلس کے پیش نظر صرف ترمیمِ نصاب کا سوال ہے‘ اور غالبًا یہ سمجھا جارہا ہے کہ چند کتابوں کو خارج کر کے چند دوسری کتابیں رکھ دینے سے طلبہ میں ’اسلامی اسپرٹ‘ پیدا کی جاسکتی ہے۔ اگر میرا قیاس صحیح ہے تو میں کہوں گا کہ یہ اصلی صورت حال کا بہت ہی نامکمل اندازہ ہے۔ دراصل ہم کو اس سے زیادہ گہرائی میں جاکر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن‘ حدیث‘ فقہ اورعقائد کی اس تعلیم کے باوجود جو اس وقت دی جارہی ہے‘طلبا میں ’’حقیقی اسلامی اسپرٹ‘‘ پیدا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اگر محض موجودہ نصاب دینیات کا نقص ہی اس کی وجہ ہے تو اس نقص کو دور کرنا بلاشبہ اس خرابی کو رفع کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا، لیکن اگر اس کے اسباب زیادہ وسیع ہیں‘ اگر آپ کی پوری تعلیمی پالیسی میں کوئی اساسی خرابی موجود ہے تو اصلاح حال کے لیے محض نصاب دینیات کی ترمیم ہرگز کافی نہ ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اصلاحات کا دائرہ زیادہ وسیع کرنا ہوگا۔ خواہ وہ کتنا ہی محنت طلب اور مشکلات سے لبریز ہو۔ میں نے اس مسئلے پر اسی نقطہ نظر سے غور کیا ہے‘ اور جن نتائج پر میں پہنچا ہوں انھیں امکانی اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔
میرا یہ بیان تین حصوں مشتمل ہوگا:
• پہلے حصے میں یونی ورسٹی کی موجودہ تعلیمی پالیسی پر تنقیدی نظر ڈال کر اس کی اساسی خرابیوں کو واضح کیا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے حقیقی مفاد کے لیے اب ہماری تعلیمی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔
• دوسرے حصے میں اصلاحی تجاویز پیش کی جائیں گی۔
• اور تیسرے حصے میں ان تجاویز کو عملی جامہ پہنانے کی تدابیر سے بحث کی جائے گی۔
اس وقت مسلم یونی ورسٹی میں جو طریق تعلیم رائج ہے وہ تعلیمِ جدید اور اسلامی تعلیم کی ایک ایسی آمیزش پر مشتمل ہے جس میں کوئی امتزاج اور کوئی ہم آہنگی نہیں۔ دو بالکل متضاد اور بے جوڑ تعلیمی عنصروں کو جوں کا توں لے کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ان میں یہ صلاحیت پیدا نہیں کی گئی کہ ایک مرکب علمی قوت بن کر کسی ایک کلچر کی خدمت کرسکیں۔ یک جائی و اجتماع کے باوجود یہ دونوں عنصر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں‘ بلکہ ایک دوسرے کی مزاحمت کرکے طلبہ کے ذہن کو دو مخالف سمتوں کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر سے قطع نظر‘ خالص تعلیمی نقطہ نگاہ سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا پڑے گا کہ تعلیم میں اس قسم کے متبائن اور متزاحم عناصرکی آمیزش اصلاً غلط ہے‘ اور اس سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوسکتا۔
اسلامی نقطہ نظر سے یہ آمیزش اور بھی زیادہ قباحت کا سبب بن گئی ہے‘کیونکہ اول تو خود آمیزش ہی درست نہیں ہے‘پھر اس پر مزید خرابی یہ ہے کہ آمیزش بھی مساویانہ نہیں ہے۔ اس میں مغربی عنصر بہت طاقت ور اور اسلامی عنصر اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ مغربی عنصر کو پہلا فائدہ تو یہ حاصل ہے کہ وہ ایک عصری عنصر ہے جس کی پشت پر رفتار زمانہ کی قوت اور ایک عالم گیر حکمراں تمدن کی طاقت ہے۔ اس کے بعد وہ ہماری یونی ورسٹی کی تعلیم میں ٹھیک اسی شان اور اسی طاقت کے ساتھ شریک کیا گیا ہے جس کے ساتھ وہ ان یونی ورسٹیوں میں ہے اور ہونا چاہیے جو مغربی کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہیں۔ یہاں مغربی علوم و فنون کی تعلیم اس طور پر دی جاتی ہے کہ ان کے تمام اصول اور نظریات مسلمان لڑکوں کے صاف اور سادہ لوح دل پر ایمان بن کر ثبت ہو جاتے ہیں اور ان کی ذہنیت کلیۃً مغربی سانچے میں ڈھل جاتی ہے‘ حتیٰ کہ وہ مغربی نظر سے دیکھنے اور مغربی دماغ سے سوچنے لگتے ہیں‘ اور یہ اعتقاد ان پر مسلط ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز معقول اور باوقعت ہے تو وہی ہے جو مغربی حکمت کے اصول و مبادی سے مطابقت رکھتی ہو۔ پھر ان تاثرات کو مزید تقویت اس تربیت سے پہنچتی ہے جو ہماری یونی ورسٹی میں عملاً دی جارہی ہے۔ لباس‘ معاشرت‘ آداب و اطوار‘ رفتار و گفتار‘ کھیل کود‘ غرض کون سی چیز ہے جس پر مغربی تہذیب و تمدن اور مغربی رجحانات کا غلبہ نہیں ہے۔ یونی ورسٹی کا ماحول اگر پورا نہیں تو ۹۵ فی صدی یقیناًمغربی ہے اور ایسے ماحول کے جو اثرات ہوسکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں ان کو ہر صاحب نظر خود سمجھ سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی عنصر نہایت کمزور ہے۔ اول تو وہ اپنی تمدنی و سیاسی طاقت کھوکر ویسے ہی کمزور ہو چکا ہے۔ پھر ہماری یونی ورسٹی میں اس کی تعلیم جن کتابوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے وہ موجودہ زمانے سے صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں۔ ان کی زبان اور ترتیب و تدوین ایسی نہیں جو عصری دماغوں کو اپیل کرسکے۔ ان میں اسلام کے ابدی اصولوں کو جن حالات اور جن عملی مسائل پر منطبق کیا گیا ہے‘ ان میں سے اکثر اب در پیش نہیں ہیں‘ اور جو مسائل اب درپیش ہیں ان پر ان اصولوں کو منطبق کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مزید براں اس تعلیم کی پشت پر کوئی تربیت‘ کوئی زندہ ماحول‘ عملی برتاؤ اور چلن بھی نہیں۔ اس طرح مغربی تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کی آمیزش اور بھی زیادہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ ایسی نامساوی آمیزش کا طبیعی نتیجہ یہ ہے کہ طلبا کے دل و دماغ پر مغربی عنصر پوری طرح غالب آجائے اور اسلامی عنصر محض ایک سامان مضحکہ بننے کے لیے رہ جائے‘ یا زیادہ سے زیادہ اس لیے کہ زمانہ ماضی کے آثار باقیہ کی طرح اس کا احترام کیا جائے۔
میں اپنی صاف گوئی پر معافی کا خواستگارہوں‘ مگر جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس کو بے کم و کاست بیان کر دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ میری نظر میں مسلم یونی ورسٹی کی دینی و دنیاوی تعلیم بحیثیت مجموعی بالکل ایسی ہے کہ آ پ ایک شخص کو از سر تا پا غیر مسلم بناتے ہیں۔ پھر اس کی بغل میں دینیات کی چند کتابوں کا ایک بستہ دے دیتے ہیں‘ تاکہ آپ پر اسے غیر مسلم بنانے کا الزام عائد نہ ہو‘ اور اگر وہ اس بستے کو اٹھا کر پھینک دے (جس کی وجہ دراصل آپ ہی کی تعلیم ہوگی) تو وہ خود ہی اس فعل کے لیے قابل الزام قرار پائے۔ اس طرز تعلیم سے اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ مسلمان پیدا کرے گا تو یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ آپ معجزے اور خرقِ عادت کے متوقع ہیں کیونکہ آپ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں ان سے قانونِ طبیعی کے تحت تو یہ نتیجہ کبھی برآمد نہیں ہوسکتا۔ فی صدی ایک یا دو چار طالب علموں کا مسلمان (کامل اعتقادی و عملی مسلمان) رہ جانا کوئی حجت نہیں۔ یہ آپ کی یونی ورسٹی کے فیضانِ تربیت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ اس کا ثبوت ہے کہ جو اس فیضان سے اپنے ایمان و اسلام کو بچا لے گیا وہ دراصل فطرت ابراہیمی پر پیدا ہوا تھا۔ ایسے مستثنیات جس طرح علی گڑھ کے فارغ التحصیل اصحاب میں پائے جاتے ہیں، اسی طرح ہندستان کی سرکاری یونی ورسٹیوں، بلکہ یورپ کی یونی ورسٹیوں کے مُتَخَرِجِیْن میں بھی مل سکتے ہیں جن کے نصاب میں سرے سے کوئی اسلامی عنصر ہے ہی نہیں۔
اب اگر آپ ان حالات اور اس طرز تعلیم کو بعینہ باقی رکھیں اور محض دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقت ور نصاب شریک کر دیں تو اس کا حاصل صرف یہ ہوگا کہ فرنگیت اور اسلامیت کی کشمکش زیادہ شدید ہو جائے گی۔ ہر طالب علم کا دماغ ایک رزم گاہ بن جائے گا جس میں یہ دو طاقتیں پوری طاقت کے ساتھ جنگ کریں گی اور بالاخر آپ کے طلبا تین مختلف گروپوں میں بٹ جائیں گے
• ایک وہ جن پر فرنگیت غالب رہے گی‘ عام اس سے کہ وہ انگریزیت کے رنگ میں ہو‘ یا ہندی وطن پرستی کے رنگ میں، یا ملحدانہ اشتراکیت کے رنگ میں۔
• دوسرے وہ جن پر اسلامیت غالب رہے گی‘ خواہ اس کا رنگ گہرا ہو یا فرنگیت کے اثر سے پھیکا پڑ جائے۔
• تیسرے وہ جو نہ پورے مسلمان ہوں گے، نہ پورے فرنگی۔
ظاہر ہے کہ تعلیم کا یہ نتیجہ بھی کوئی خوشگوار نتیجہ نہیں۔ نہ خالص تعلیمی نقطہ نظر سے اس اجتماعِ نقیضین کو مفید کہا جاسکتا ہے‘ اور نہ قومی نقطہ نظر سے ایسی یونی ورسٹی اپنے وجود کو حق بجانب ثابت کرسکتی ہے جس کے نتائج کا ۳/ ۲ حصہ قومی مفاد کے خلاف اور قومی تہذیب کے لیے نقصانِ کامل کا مترادف ہو۔ کم از کم مسلمانوں کی غریب قوم کے لیے تو یہ سودا بہت ہی مہنگا ہے کہ وہ لاکھوں روپے کے خرچ سے ایک ایسی ٹکسال جاری رکھے جس میں سے ۳۳ فی صدی سکے تو مستقل طور پر کھوٹے نکلتے رہیں‘ اور ۳۳ فی صدی ہمارے خرچ پر تیار ہو کر غیروں کی گود میں ڈال دیے جائیں‘ بلکہ بالآخر خود ہمارے خلاف استعمال ہوں۔
مذکورہ بالا بیان سے دو باتیں اچھی طرح واضح ہو جاتی ہیں:
• اولاً تعلیم میں متضاد عناصر کی آمیزش اصولی حیثیت سے غلط ہے۔
• ثانیاً اسلامی مفاد کے لیے بھی ایسی آمیزش کسی طرح مفید نہیں‘ خواہ وہ اس قسم کی غیرمساوی آمیزش ہو۔ جیسی اب تک رہی ہے‘ یا مساوی کر دی جائے‘ جیسا کہ اب کرنے کا خیال کیا جارہا ہے۔
ان امور کی توضیح کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری رائے میں یونی ورسٹی کی تعلیمی پالیسی اب کیا ہونی چاہیے۔
یہ ظاہر ہے کہ ہر یونی ورسٹی کسی کلچر کی خادم ہوتی ہے۔ ایسی مجرد تعلیم جو ہر رنگ اور ہر صورت سے خالی ہو، نہ آج تک دنیا کی کسی درس گاہ میں دی گئی ہے‘ نہ آج دی جاری ہے۔ ہر درس گاہ کی تعلیم ایک خاص رنگ اور ایک خاص صورت میں ہوتی ہے اور اس رنگ و صورت کا انتخاب پورے غور و فکر کے بعد، اس مخصوص کلچر کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کی خدمت وہ کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کی یونی ورسٹی کس کلچر کی خدمت کے لیے قائم کی گئی ہے۔ اگر وہ مغربی کلچر ہے تو اس کو مسلم یونی ورسٹی نہ کہیے‘ نہ اس میں دینیات کا ایک نصاب رکھ کر خواہ مخواہ طالب علموں کو ذہنی کش مکش میں مبتلا کیجیے، اور اگر وہ اسلامی کلچر ہے تو آپ کو اپنی یونی ورسٹی کی پوری ساخت بدلنی پڑے گی اور اس کی ہیئتِ ترکیبی کو ایسے طرز پر ڈھالنا ہوگا کہ وہ بحیثیت مجموعی اس کلچر کے مزاج اور اس کی اسپرٹ کے مناسب ہو‘ اور نہ صرف اس کا تحفظ کرے بلکہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھی طاقت بن جائے۔
جیسا کہ میں اوپر ثابت کر چکا ہوں کہ موجودہ حالت میں تو آپ کی یونی ورسٹی اسلامی کلچر کی نہیں بلکہ مغربی کلچر کی خادم بنی ہوئی ہے۔ اس حالت میں اگر صرف اتنا تغیر کیا جائے کہ دینیات کے موجودہ نصاب کو بدل کر زیادہ طاقت ور کر دیا جائے اور تعلیم و تربیت کے باقی تمام شعبوں میں پوری مغربیت برقرار رہے تو اس سے بھی یہ درس گاہ اسلامی کلچر کی خادم نہیں بن سکتی۔ اسلام کی حقیقت پر غور کرنے سے یہ بات خود بخود آپ پر منکشف ہو جائے گی کہ دنیوی تعلیم و تربیت اور دینی تعلیم کو الگ کرنا اور ایک دوسرے سے مختلف رکھ کر ان دونوں کو یکجا جمع کر دینا بالکل لا حاصل ہے۔ اسلام مسیحیت کی طرح کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کا دین دنیا سے کوئی الگ چیز ہو۔ وہ دنیا کو دنیا والوں کے لیے چھوڑ کر صرف اعتقادات اور اخلاقیات کی حد تک اپنے دائرے کو محدود نہیں رکھتا۔اس لیے مسیحی دینیات کی طرح اسلام کے دینیات کو دنیویات سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کا اصل مقصد انسان کو دنیا میں رہنے اور دنیا کے معاملات انجام دینے کے لیے ایک ایسے طریقے پر تیار کرنا ہے‘ جو اس زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک سلامتی‘ عزت اور برتری کا طریقہ ہے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی فکر و نظر کو درست کرتا ہے۔ اس کے اخلاق کو سنوارتا ہے‘ اس کی سیرت کو ایک خاص سانچے میں ڈھالتا ہے، اس کے لیے حقوق و فرائض متعین کرتا ہے اور اس کو اجتماعی زندگی کا ایک خاص نظام وضع کر کے دیتا ہے۔
افراد کی ذہنی و عملی تربیت‘ سوسائٹی کی تشکیل و تنظیم اور زندگی کے تمام شعبوں کی تربیت و تعدیل کے باب میں اس کے اصول و ضوابط سب سے الگ ہیں۔ انھی کی بدولت اسلامی تہذیب ایک جداگانہ تہذیب کی شکل اختیار کرتی ہے‘ اور مسلمان قوم کا بحیثیت ایک قوم کے زندہ رہنا انھی کی پابندی پر منحصر ہے۔ پس جب حال یہ ہے تو ’اسلامی دینیات‘ کی اصلاح ہی بے معنی ہو جاتی ہے اگر زندگی اور اس کے معاملات سے اس کا ربط باقی نہ رہے۔ اسلامی کلچر کے لیے وہ عالم دین بے کارہے جو اسلام کے عقائد اور اصول سے واقف ہے مگر ان کو لے کر علم و عمل کے میدان میں بڑھنا اور زندگی کے دائم التغیر احوال و مسائل میں ان کو برتنا نہیں جانتا۔ اسی طرح اس کلچر کے لیے وہ عالم دین بھی بے کار ہے جو دل میں تو اسلام کی صداقت پر ایمان رکھتا ہے، مگر دماغ سے غیراسلامی طریق پر سوچتا ہے‘ معاملات کو غیر اسلامی نظر سے دیکھتا ہے اور زندگی کو غیر اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے۔ اسلامی تہذیب کے زوال اور اسلامی نظام تمدن کی ابتری کا اصل سبب یہی ہے کہ ایک مدت سے ہماری قوم میں صرف انھی دو قسموں کے عالم پیدا ہو رہے ہیں‘ اور دنیوی علم و عمل سے علم دین کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔
اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی کلچر پھر سے جوان ہو جائے اور زمانے کے پیچھے چلنے کے بجائے آگے چلنے لگے‘ تو اس ٹوٹے ہوئے رابطہ کو پھر قائم کیجیے، مگر اس کو قائم کرنے کی صورت یہ نہیں ہے کہ دینیات کے نصاب کو جسم تعلیمی کی گردن کا قلاوہ یا کمر کا پشتارہ بنا دیا جائے۔ نہیں، اس کو پورے نظام تعلیم و تربیت میں اس طرح اتار دیجیے کہ وہ اس کا دوران خون‘ اس کی روح رواں، اس کی بینائی و سماعت‘ اس کا احساس و ادراک‘ اس کا شعور و فکر بن جائے‘ اور مغربی علوم و فنون کے تمام صالح اجزا کو اپنے اندر جذب کرکے اپنی تہذیب کا جز بناتا چلا جائے۔ اس طرح آپ مسلمان فلسفی‘ مسلمان سائنس دان‘ مسلمان ماہرین معاشیات‘ مسلمان مقنن‘ مسلمان مدبرین‘ غرض تمام علوم و فنون کے مسلمان ماہر پیدا کرسکیں گے جو زندگی کے مسائل کو اسلامی نقطہ نظر سے حل کریں گے‘ تہذیب حاضر کے ترقی یافتہ اسباب و وسائل سے تہذبِ اسلامی کی خدمت لیں گے‘ اور اسلام کے افکار و نظریات اور قوانین حیات کو روح عصری کے لحاظ سے از سر نو مرتب کریں گے‘ یہاں تک کہ اسلام از سر نو علم و عمل کے ہر میدان میں اسی امامت و رہنمائی کے مقام پر آجائے گا جس کے لیے وہ درحقیقت دنیا میں پیدا کیا گیا ہے۔
یہ ہے وہ تخیل جو مسلمانوں کی جدید تعلیمی پالیسی کا اساسی تخیل ہونا چاہیے۔ زمانہ اس مقام سے بہت آگے نکل چکا ہے جہاں سرسید ہم کو چھوڑ گئے تھے۔ اب اگر زیادہ عرصے تک ہم اس پر قائم رہے تو بحیثیت ایک مسلم قوم کے ہمارا ترقی کرنا تو درکنار‘ زندہ رہنا بھی مشکل ہے۔
(۲)
اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اوپر جس تعلیمی پالیسی کا ہیولیٰ میں نے پیش کیا ہے اس کو صورت کالباس کس طرح پہنایا جاسکتا ہے۔
۱۔ مسلم یونی ورسٹی کے حدود میں ’فرنگیت‘ کا کلی استیصال کر دینا نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی قومی تہذیب کو اپنے ہاتھوں قتل کرنا نہیں چاہتے تو ہمارا فرض ہے کہ اپنی نئی نسلوں میں فرنگیت کے ان روز افزوں رجحانات کا سدباب کریں۔ یہ رجحانات دراصل غلامانہ ذہنیت اور چھپی ہوئی احساس ونائت (Inferiority complex)کی پیداوار ہیں۔ پھر جب ان کا عملی ظہور‘ لباس‘ معاشرت‘ آداب و اطوار اور بحیثیت مجموعی پورے ماحول میں ہوتا ہے تو یہ ظاہر اور باطن دونوں طرف سے نفس کا احاطہ کر لیتے ہیں‘ اور اس میں شرفِ قومی کا رمق برابر احساس نہیں چھوڑتے۔ ایسے حالات میں اسلامی تہذیب کا زندہ رہنا قطعی ناممکن ہے۔ کوئی تہذیب محض اپنے اصولوں اور اپنے اساسی تصورات کے مجرد ذہنی وجود سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ عملی برتاؤں سے پیدا ہوتی ہے اور اسی سے نشوونما پاتی ہے۔ اگر عملی برتاؤ مفقود ہو جائے تو تہذیب اپنی طبیعی موت مرجائے گی‘ اور اس کا ذہنی وجود بھی برقرار نہ رہ سکے گا۔ پس سب سے مقدم اصلاح یہ ہے کہ یونی ورسٹی میں ایک زندہ اسلامی ماحول پیدا کیا جائے۔ آپ کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جو مسلمانوں کی نئی نسلوں کو اپنی قومی تہذیب پر فخر کرنا سکھائے‘ ان میں اپنی قومی خصوصیات کا احترام بلکہ عشق پیدا کرے‘ ان میں اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کی روح پھونک دے‘ ان کو اس قابل بنا دے کہ وہ اپنے علم اور اپنی تربیت یافتہ ذہنی صلاحیتوں سے اپنے قومی تمدن کو شائستگی کے بلند مدارج کی طرف لے چلیں۔
۲۔ اسلامی اسپرٹ پیدا کرنے کا انحصار بڑی حد تک معلمین کے علم و عمل پر ہے۔ جو معلم خود اس روح سے خالی ہیں‘ بلکہ خیال اورعمل دونوں میں اس کے مخالف ہیں ان کے زیر اثر رہ کر متعلمین میں اسلامی اسپرٹ کیسے پیدا ہوسکتی ہے؟ آپ محض عمارت کا نقشہ بنا سکتے ہیں‘ مگر اصلی معمار آپ نہیں، آپ کے تعلیمی اسٹاف کے ارکان ہیں۔ فرنگی معماروں سے یہ امید رکھنا کہ وہ اسلامی طرز تعمیرپر عمارت بنائیں گے‘ کریلے کی بیل سے خوشۂ انگور کی امید رکھنا ہے۔ محض دینیات کے لیے چند ’مولوی‘ رکھ لینا ایسی صورت میں بالکل فضول ہوگا جب کہ دوسرے تمام یا اکثر علوم کے پڑھانے والے غیر مسلم یا ایسے مسلمان ہوں جن کے خیالات غیر اسلامی ہوں، کیونکہ وہ زندگی اور اس کے مسائل اور معاملات کے متعلق طلبا کے نظریات اور تصورات کو اسلام کے مرکز سے پھیر دیں گے‘ اور اس زہر کا تریاق محض دینیات کے کورس سے فراہم نہ ہوسکے گا۔ لہٰذا خواہ کوئی فن ہو‘ فلسفہ ہو یا سائنس‘ معاشیات ہو یا قانون‘ تاریخ ہو یا کوئی اور علم‘ مسلم یونی ورسٹی میں اس کی پروفیسری کے لیے کسی شخص کا محض ماہر فن ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ پورا اورپکا مسلمان ہو۔ اگر مخصوص حالات میں کسی غیر مسلم ماہر فن کی خدمات حاصل کرنی پڑیں تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن عام قائدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہماری یونی ورسٹی کے پروفیسر وہ لوگ ہوں جو اپنے فن میں ماہر ہونے کے علاوہ یونی ورسٹی کے اساسی مقصد یعنی اسلامی کلچر کے لیے خیالات اور اعمال دونوں کے لحاظ سے مفید ہوں۔
۳۔ یونی ورسٹی کی تعلیم میں عربی زبان کو بطور ایک لازمی زبان کے شریک کیا جائے۔ یہ ہمارے کلچر کی زبان ہے۔ اسلام کے مآخذ اصلیہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ جب تک مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ قرآن اور سنت تک بلاواسطہ دسترس حاصل نہ کرے گا‘ اسلام کی روح کو نہ پاسکے گا‘ نہ اسلام میں بصیرت حاصل کرسکے گا۔ وہ ہمیشہ مترجموں اور شارحوں کا محتاج رہے گا‘ اور اس طرح کی روشنی اس کو براہِ راست آفتاب سے کبھی نہ مل سکے گی، بلکہ مختلف قسم کے رنگین آئینوں کے واسطے ہی سے ملتی رہے گی‘ آج ہمارے جدید تعلیم یافتہ حضرات اسلامی مسائل میں ایسی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی ابجد تک سے ناواقف ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے استفادہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں رکھتے۔آگے چل کر پراونشل اٹانومی کے دور میں جب ہندستان کی مجالس مقننہ کو قانون سازی کے زیادہ وسیع اختیارات حاصل ہوں گے اور سوشل رفارم کے لیے نئے نئے قوانین بنائے جانے لگیں گے۔ اس وقت اگر مسلمانوں کی نمائندگی ایسے لوگ کرتے رہے جو اسلام سے ناواقف ہوں اور اخلاق‘ معاشرت اور قانون کے مغربی تصورات پر اعتقاد رکھتے ہوں‘ تو جدید قانون سازی سے مسلمانوں میں سوشل ریفارم ہونے کے بجائے انٹی سوشل ڈیفارم ہوگی اور مسلمانوں کا اجتماعی نظام اپنے اصولوں سے اور زیادہ دور ہوتا چلا جائے گا۔ پس عربی زبان کے مسئلے کو محض ایک زبان کا مسئلہ نہ سمجھیے‘ بلکہ یوں سمجھیے کہ یہ آپ کی یونی ورسٹی کے اساسی مقصد سے تعلق رکھتا ہے اور جو چیز اساسیات (Funadamentals)سے تعلق رکھتی ہو اس کے لیے سہولت کا لحاظ نہیں کیا جاتا‘ بلکہ ہر حال میں اس کی جگہ نکالنی پڑتی ہے۔
۴۔ ہائی اسکول کی تعلیم میں طلبہ کو حسب ذیل مضامین کی ابتدائی معلومات حاصل ہونی چاہییں۔
الف۔ عقائد
اس مضمون میں عقائد کی خشک کلامی تفصیلات نہ ہونی چاہییں، بلکہ ایمانیات کو ذہن نشین کرنے کے لیے نہایت لطیف انداز بیان اختیارکرنا چاہیے جو فطری وجدان اورعقل کو اپیل کرنے والا ہو۔
طلبہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ایمانیات دراصل کائنات کی بنیادی صداقتیں ہیں اور یہ صداقتیں ہماری زندگی سے ایک گہرا ربط رکھتی ہیں۔
ب۔ اسلامی اخلاق
اس مضمون میں مجرد اخلاقی تصورات نہ پیش کیے جائیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور انبیاء علیھم السلام کی سیرتوں سے ایسے واقعات لے کر جمع کیے جائیں جن سے طلبا کو معلوم ہو کہ ایک مسلمان کے کریکٹر کی خصوصیات کیا ہیں اور مسلمان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔
ج۔احکام فقہ
اس مضمون میں حقوق اللہ اور حقوق العباد اور شخصی کردار کے متعلق اسلامی قانون کے ابتدائی اور ضروری احکام بیان کیے جائیں جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ناگزیر ہے، مگر اس قسم کے جزئیات اس میں نہ ہونے چاہییں جیسے ہماری فقہ کی پرانی کتابوں میں آتے ہیں کہ مثلاً کنویں میں چوہا گر جائے تو کتنے ڈول نکالے جائیں۔ ان چیزوں کے بجائے عبادات اور احکام کی معنویت‘ ان کی روح اور ان کے مصالح طلبہ کے ذہن نشین کرنے چاہییں۔ ان کو یہ بتانا چاہیے اسلام تمھارے لیے انفرادی اور اجتماعی زندگی کا کیا پروگرام بتاتا ہے اور یہ پروگرام کس طرح ایک صالح سوسائٹی کی تخلیق کرتا ہے۔
د۔ اسلامی تاریخ
یہ مضمون صرف سیرت رسولؐ اور دور صحابہؓ تک محدود رہے۔ اس کے پڑھانے کی غرض یہ ہونی چاہیے کہ طلبہ اپنے مذہب اور اپنی قومیت کی اصل سے واقف ہو جائیں اور ان کے دلوں میں اسلامی حمیت کا صحیح احساس پیدا ہو۔
ر۔عربیت
عربی زبان کا محض ابتدائی علم جو ادب سے ایک حد تک مناسبت پیدا کر دے۔
س۔قرآن صرف اتنی استعداد کہ لڑکے کتاب اللّٰہ کو روانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ سادہ آیتوں کو کسی حد تک سمجھ سکیں اور چند سورتیں بھی ان کو یاد ہوں۔
(۵) کالج کی تعلیم میں ایک نصاب عام ہونا چاہیے جو تمام طلبہ کو پڑھایا جائے۔ اس نصاب میں حسب ذیل مضامین ہونے چاہییں۔
الف۔ عربیت انٹرمیڈیٹ میں عربی ادب کی متوسط تعلیم ہو۔ بی اے میں پہنچ کر اس مضمون کو تعلیم قرآن کے ساتھ ضم کر دیا جائے۔
ب۔ قرآن انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کو فہم قرآن کے لیے مستعد کیا جائے۔ اس مرحلے میں صرف چند مقدمات ذہن نشین کرا دینے چاہئییں۔ قرآن کا محفوظ اور تاریخی حیثیت سے معتبر ترین کتاب ہونا۔ اس کا وحی الٰہی ہونا۔ تمام مذاہب کی اساسی کتابوں کے مقابلے میں اس کی فضیلت۔ اس کی بے نظیر انقلاب انگیز تعلیم۔ اس کے اثرات نہ صرف عرب پر بلکہ تمام دنیا کے افکار اور قوانینِ حیات پر۔ اس کا انداز بیان اور طرزاستدلال۔ اس کا حقیقی مدعا۔
بی۔ اے میں اصل قرآن کی تعلیم دی جائے۔ یہاں طرز تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ طلبا خود قرآن کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور استاد ان کی مشکلات کو حل اور ان کے شبہات کو رفع کرتا جائے۔ اگر مفصل تفسیر اور جزئی بحثوں سے اجتناب ہو، اور صرف مطالب کی توضیح پر اکتفا کیا جائے تو دو سال میں با آسانی پورا قرآن پڑھایا جاسکتا ہے۔
ج۔ تعلیمات اسلامی اس مضمون میں طلبہ کو پورے نظام اسلامی سے روشناس کرا دیا جائے۔ اسلام کی بنیاد کن اساسی تصورات پر قائم ہے۔ ان تصورات کی بنا پر وہ اخلاق اور سیرت کی تشکیل کس طرح کرتا ہے۔ پھر اس سوسائٹی کی زندگی کو وہ معاشرت‘ معیشت‘ سیاست اور بین الاقوامی تعلقات میں کن اصولوں پر منظم کرتا ہے۔ اس کے اجتماعی نظام میں فرد اور جماعت کے درمیان حقوق و فرائض کی تقسیم کس ڈھنگ پر کی گئی ہے۔ حدود اللہ کیا ہیں۔ ان حدود کے اندر مسلمان کو کس حد تک فکرو عمل کی آزادی حاصل ہے اور ان حدود کے باہر قدم نکالنے سے نظام اسلامی پر کیا اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ یہ تمام امور جامعیت کے ساتھ نصاب میں لائے جائیں اور اس کو چار سال کے مدارج تعلیمی پر ایک مناسبت کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے۔
۶۔ نصاب عام کے بعد علوم اسلامیہ کو تقسیم کرکے مختلف علوم و فنون کی اختصاصی تعلیم میں پھیلا دیجیے اور ہر فن میں اسی فن کی مناسبت سے اسلام کی تعلیمات کو پیوست کیجیے۔ مغربی علوم و فنون بجائے خود سب کے سب مفید ہیں‘ اور اسلام کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی دشمنی نہیں‘ بلکہ جواباً میں یہ کہوں گا کہ جہاں تک حقائق علمیہ کا تعلق ہے اسلام ان کا دوست ہے اور وہ اسلام کے دوست ہیں۔ دشمنی دراصل علم اور اسلام میں نہیں بلکہ مغربیت اور اسلام میں ہے۔ اکثر علوم میں اہل مغرب اپنے چند مخصوص اساسی تصورات‘ بنیادی مفروضات (Hypothesis)،نقطہ ہائے آغاز(Starting Points)اور زاویہ حائے نظر رکھتے ہیں جو بجائے خود ثابت شدہ حقائق نہیں ہیں بلکہ محض ان کے اپنے وجدانیات ہیں۔ وہ حقائق علمیہ کو اپنے ان وجدانیات کے سانچے میں ڈھالتے ہیں‘ اور اس سانچے کی مناسبت سے ان کو مرتب کرکے ایک مخصوص نظام بنا لیتے ہیں۔ اسلام کی دشمنی دراصل انھی وجدانیات سے ہے۔ وہ حقائق کا دشمن نہیں بلکہ اس وجدانی سانچے کا دشمن ہے جس میں ان حقائق کو ڈھالا اور مرتب کیا جاتا ہے۔ وہ خود اپنا ایک مرکزی تصور‘ ایک زاویۂ نظر‘ ایک نقطہ آغاز فکر، ایک وجدانی سانچہ رکھتا ہے جو اپنی اصل اور فطرت کے اعتبار سے مغربی سانچوں کی عین ضد واقع ہوا ہے۔
اب یہ سمجھ لیجیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے ضلالت کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ مغربی علوم و فنون سے حقائق لیتے ہیں‘ بلکہ یہ ہے کہ آپ مغرب ہی سے اس کا وجدانی سانچہ بھی لے لیتے ہیں۔ فلسفہ‘ سائنس‘ تاریخ‘ قانون‘ سیاسیات‘ معاشیات اور دوسرے علمی شعبوں میں آپ خود ہی تو اپنے نوجوان اور خالی الذہن طلبا کے دماغوں میں مغرب کے اساسی تصورات بٹھاتے ہیں‘ ان کی نظر کا فوکس مغربی زاویہ نظر کے مطابق جماتے ہیں‘ مغربی مفروضات کو مسلمات بناتے ہیں۔ استدلال و استشہاد اور تحقیق و تفحیص کے لیے صرف وہی ایک نقطہ آغاز ان کو دیتے ہیں جو اہل مغرب نے اختیار کیا ہے اور تمام علمی حقائق اور مسائل کو اسی طرز پر مرتب کرکے ان کے ذہن میں اتار دیتے ہیں جس طرز پر اہل مغرب نے ان کو مرتب کیا ہے۔ اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ تنہا دینیات کا شعبہ انھیں مسلمان بنا دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ شعبہ دینیات کیا کرسکتا ہے جس مں مجرد تصورات ہوں۔ حقائقِ علمیہ اور مسائلِ حیات پر ان تصورات کا انطباق نہ ہو بلکہ طلبہ کے ذہن میں جملہ معلومات کی ترتیب ان تصورات کے بالکل برعکس ہو۔ یہی گمراہی کا سرچشمے ہے۔ اگر آپ گمراہی کا سدباب کرنا چاہتے ہیں تو اس سرچشمے کے مصدر پر پہنچ کر اس کا رخ پھیر دیجیے اور تمام علمی شعبوں کو وہ نقطہ آغاز‘ وہ زاویہ نظر‘ وہ اساسی اصول دیجیے جو قرآن نے آپ کودیے ہیں۔ جب اسی وجدانی سانچے میں معلومات مرتب ہوں گی اور اس نظر سے کائنات اور زندگی کے مسائل کو حل کیا جائے گا تب آپ کے طلبہ ’مسلم طلبہ‘ بنیں گے اور آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان میں اسلامی سپرٹ پیدا کی، ورنہ ایک شعبے میں اسلام اور باقی تمام شعبوں میں غیر اسلام رکھ دینے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ آپ کے فارغ التحصیل طلبہ فلسفہ میں غیر مسلم‘ سائنس میں غیر مسلم‘ قانون میں غیر مسلم‘ سیاسیات میں غیر مسلم‘ فلسفہ تاریخ میں غیر مسلم‘ معاشیات میں غیر مسلم ہوں گے اور ان کا اسلام محض چند اعتقادات اور چند مذہبی مراسم کی حد تک محدود رہ جائے گا۔
۷۔ بی‘ ٹی‘ ایچ اور ایم‘ ٹی‘ ایچ کے امتحانات کو بند کر دیجیے۔ نہ ان کی کوئی ضرورت، نہ فائدہ۔ جہاں تک علوم اسلامیہ کے مخصوص شعبوں کا تعلق ہے ان میں سے ہر ایک شعبے کو اسی کے مماثل علم کے مغربی شعبے کے انتہائی کورس میں داخل کر دیجیے۔ مثلاً فلسفے میں حکمت اسلامیہ اور اسلامی فلسفے کی تاریخ اور فلسفیانہ افکار کے ارتقا میں مسلمانوں کا حصہ۔ تاریخ میں تاریخ اسلام اور اسلامی فلسفہ تاریخ‘ قانون میں اسلامی قانون کے اصول اور فقہ کے وہ ابواب جو معاملات سے متعلق ہیں۔ معاشیات میں اسلامی معاشیات کے اصول اور فقہ کے وہ حصے جو معاشی مسائل سے متعلق ہیں۔ سیاسیات میں اسلام کے نظریات سیاسی اور اسلامی سیاسیات کے نشووارتقا کی تاریخ اور دنیا کے سیاسی افکار کی ترقی میں اسلام کا حصہ۔ (قس علیٰ ھذا)
۸۔ اس کورس کے بعد علوم اسلامیہ میں ریسرچ کے لیے ایک مستقل شعبہ ہونا چاہیے جو مغربی یونی ورسٹیوں کی طرح اعلیٰ درجے کی علمی تحقیق پر سند فضیلت (Doctrate)دیا کرے۔ اس شعبے میں ایسے لوگ تیار کیے جائیں جو مجتہدانہ طرز تحقیق کی تربیت پا کر نہ صرف مسلمانوں کی بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے تمام دنیا کی نظری و فکری رہنمائی کے لیے مستعد ہوں۔
(۳)
حصہ دوم میں جس طرز تعلیم کا خاکہ میں نے پیش کیا ہے وہ بظاہر ناقابل عمل معلوم ہوتا ہے لیکن میں کافی غور و خوض کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ توجہ اور محنت اور صَرف مال سے اس کو بتدریج عمل میں لایا جاسکتا ہے۔
یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کسی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہی منزل کے آخری نشان پر نہیں پہنچ سکتے۔ کام کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی تکمیل کا پورا سامان پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو۔ ابھی تو آپ کو صرف عمارت کی بنیاد رکھنی ہے‘ اور اس کا سامان اس وقت فراہم ہوسکتا ہے۔ موجودہ نسل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرز تعمیر پر بنیادیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت سے جو نسل اٹھے گی وہ دیواریں اٹھانے کے قابل ہوگی۔ پھر تیسری نسل ایسی نکلے گی جس کے ہاتھوں یہ کام ان شاء اللہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ جو درجہ کمال کم از کم تین نسلوں کی مسلسل محنت کے بعد حاصل ہوسکتا ہے‘ اس کو آج ہی حاصل کرلینا ممکن نہیں، لیکن تیسری نسل میں عمارت کی تکمیل تب ہی ہوسکے گی کہ آپ آج اس کی بنیاد رکھ دیں، ورنہ اگر اس کے درجۂ کمال کو اپنے سے دور پاکر آپ نے آج سے اس کی ابتدا ہی نہ کی، حالانکہ ابتدا کرنے کے اسباب آپ کے پاس موجود ہیں‘ تو یہ کام کبھی انجام نہ پائے گا۔
چونکہ میں اس اصلاحی اقدام کا مشورہ دے رہا ہوں اس لیے یہ بھی میرا فرض ہے کہ اس کو عمل میں لانے کی تدابیر بھی پیش کروں۔ اپنے بیان کے اس حصے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرز تعلیم کی ابتدا کس طرح کی جاسکتی ہے اور اس کے لیے قابل عمل تدبیریں کیا ہیں
۱۔ ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے عقائد‘ اسلامی اخلاق اور احکام شریعت کا ایک جامع کورس حال ہی میں سرکار نظام کے محکمہ تعلیمات نے تیار کرایا ہے اس کو ضروری ترمیم و اصلاح سے بہت کار آمد بنایا جاسکتا ہے۔
عربی زبان کی تعلیم قدیم طرز کی وجہ سے جس قدر ہولناک ہوگئی تھی الحمد للہ کہ اب وہ کیفیت باقی نہیں رہی ہے۔ اس کے لیے جدید طریقے مصر و شام اور خود ہندستان میں ایسے نکل آئے ہیں جن سے باآسانی یہ زبان سکھائی جاسکتی ہے۔ ایک خاص کمیٹی ان لوگوں کی مقرر کی جائے جو عربی تعلیم کے جدید طریقوں میں علمی و عملی مہارت رکھتے ہیں اور ان کے مشورے سے ایک ایسا کورس تجویز کیا جائے جس میں زیادہ تر قرآن ہی کو عربی کی تعلیم کا ذریعہ بنایا گیا ہو۔ اس طرح تعلیم قرآن کے لیے الگ وقت نکالنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی، اور ابتدا ہی سے طلبہ کو قرآن سے مناسبت پیدا ہو جائے گی۔
اسلامی تاریخ کے بکثرت رسالے اردو زبان میں لکھے جاچکے ہیں۔ ان کو جمع کر کے بنظر غور دیکھا جائے اور جو رسائل مفید پائے جائیں ان کو ابتدائی جماعتوں کے کورس میں داخل کرلیا جائے۔
مقدم الذکر دونوں مضامین کے لیے روزانہ صرف ایک گھنٹہ کافی ہوگا۔ رہی اسلامی تاریخ تو یہ مضمون کوئی الگ وقت نہیں چاہتا۔ تاریخ کے عمومی نصاب میں اس کو ضم کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہائی اسکول کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کوئی زیادہ تغیر کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ تغیر کی ضرورت جو کچھ بھی ہے نصاب تعلیم اور تعلیمی اسٹاف میں ہے۔ دینیات کی تدریس اور اس کے مدرس کا جو تصور آپ کے ذہن میں اب تک رہا ہے اس کو نکال دیجیے۔ اس دور کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ذہنیت اور ان کے نفسیات کو سمجھنے والے مدرس رکھیے۔ ان کو ایک ترقی یافتہ نصاب تعلیم دیجیے اور اس کے ساتھ ایسا ماحول پیدا کیجیے جس میں ’اسلامیت‘ کے بیج کو بالیدگی نصیب ہوسکے۔
۲۔ کالج کے لیے نصاب عام کی جو تجویز میں نے پیش کی ہے اس کے تین اجزا ہیں
(الف)عربیت، (ب) قرآن، (ج) تعلیمات اسلامی
ان میں سے عربیت کو آپ ثانوی لازمی زبان کی حیثیت دیجیے۔ دوسری زبانوں میں سے کسی کی تعلیم اگر طلبہ حاصل کرنا چاہیں تو ٹیوٹرس کے ذریعے سے حاصل کرسکتے ہیں، مگر کالج میں جو زبان ذریعۂ تعلیم ہے‘ اس کے بعد صرف عربی زبان ہی لازم ہونی چاہیے۔ اگر نصاب اچھا ہو اور پڑھانے والے آزمودہ کار ہوں تو انٹرمیڈیٹ کے دو سالوں میں طلبہ کے اندر اتنی استعداد پیدا کی جاسکتی ہے کہ وہ بی ۔ اے میں پہنچ کر قرآن کریم کی تعلیم خود قرآن کی زبان میں حاصل کرسکیں۔
قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا بہ نظر غائر مطالعہ کیا ہو اور جو طرز جدید پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لیکچروں سے انٹرمیڈیٹ میں طلبا کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔ پھر بی۔ اے میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دے گا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی روح سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے۔
تعلیمات اسلامی کے لیے ایک جدید کتاب لکھوانے کی ضرورت ہے جو ان مقاصد پر حاوی ہو جن کی طرف میں نے حصہ دوم کے نمبر ۵ ضمن (ج) میں اشارہ کیا ہے۔ کچھ عرصہ ہوا کہ میں نے خود اِن مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ایک کتاب اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی کے عنوان سے لکھنی شروع کی تھی جس کے ابتدائی تین باب ترجمان القرآن میں محرم ۱۳۵۲ھ سے شعبان ۱۱۳۵۳ھ تک کے پرچوں میں شائع ہوئے ہیں۔ اگر اس کو مفید سمجھا جائے تو میں اس کی تکمیل کرکے یونی ورسٹی کی نذر کردوں گا۔
ان مضامین کے لیے کالج کی تعلیم کے موجودہ نظم میں کسی تغیر کی ضرورت پیش نہ آئے گی۔ عربیت کے لیے وہی وقت کافی ہے جو آپ کے ہاں ثانوی زبان کے لیے ہے۔ قرآن اور تعلیمات اسلامیہ دونوں کے لیے باری باری سے وہی وقت کافی ہوسکتا ہے جو آپ کے ہاں دینیات کے لیے مقرر ہے۔
۳۔ زیادہ تر مشکل اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے میں پیش آئے گی جسے میں نے حصہ دوم کے نمبر۶‘ ۷ میں پیش کیا ہے۔ اس کے حل کی تین صورتیں ہیں جن کو بتدریج اختیار کیا جاسکتا ہے
الف۔ ایسے پروفیسر تلاش کیے جائیں (اور وہ ناپید نہیں ہیں) جو علوم جدیدہ کے ماہر ہونے کے ساتھ قرآن اور سنت میں بھی بصیرت رکھتے ہوں‘ جن میں اتنی اہلیت ہو کہ مغربی علوم کے حقائق کو ان کے نظریات اور ان کی وجدانی اساس سے الگ کر کے اسلامی اصول و نظریات کے مطابق مرتب کرسکیں۔
ب۔ اسلامی فلسفۂ قانون‘ اصول قانون و فلسفہ تشریع‘ سیاسیات‘ عمرانیات‘ معاشیات‘ تاریخ و فلسفہ تاریخ وغیرہ کے متعلق عربی‘ اردو‘ انگریزی‘ جرمن اور فرنچ زبانوں میں جس قدر لٹریچر موجود ہے اس کی چھان بین کی جائے۔ جو کتابیں بعینہ لینے کے قابل ہوں ان کا انتخاب کرلیا جائے اور جن کو اقتباس یا حذف و ترمیم کے ساتھ کار آمد بنایا جاسکتا ہو ان کو اسی طریق پر کام میں لایا جائے۔ اس غرض کے لیے اہل علم کی ایک خاص جمعیت مقرر کرنی ہوگی۔
ج۔ چند ایسے فضلا کی خدمات حاصل کی جائیں جو مذکورہ بالا علوم پر جدید کتابیں تالیف کریں۔ خصوصیت کے ساتھ اصول فقہ‘ احکام فقہ‘ اسلامی معاشیات‘ اسلام کے اصول عمران‘ اور حکمت قرآنیہ پر جدید کتابیں لکھنا نہایت ضروری ہے‘ کیونکہ قدیم کتابیں اب درس و تدریس کے لیے کارآمد نہیں ہیں‘ ارباب اجتہاد کے لیے تو بلاشبہ ان میں بہت اچھا مواد مل سکتا ہے مگر ان کو جوں کا توں لے کر موجود زمانے کے طلبہ کو پڑھانا بالکل بے سود ہے۔
اس میں شک نہیں کہ سردست ان تینوں تدبیروں سے وہ مقصد بدرجہ کمال حاصل نہ ہوگا جو ہمارے پیش نظر ہے۔ بلاشبہہ اس تعمیر جدید میں بہت کچھ نقائص پائے جائیں گے لیکن اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ صحیح راستے پر پہلا قدم ہوگا۔ اس میں جو کوتاہیاں رہ جائیں گی ان کو بعد کی نسلیں پورا کریں گی یہاں تک کہ اس کے تکمیلی ثمرات کم از کم پچاس سال بعد ظاہر ہوں گے۔
۴۔ اسلامی ریسرچ کا شعبہ قائم کرنے کا ابھی موقع نہیں۔ اس کی نوبت چند سال بعد آئے گی۔ اس لیے اس کے متعلق تجاویز پیش کرنا قبل از وقت ہے۔
۵۔ میری تجاویز میں فرقی اختلافات کی گنجائش بہت کم ہے۔ تاہم اس باب میں علمائے شیعہ سے استصواب کیا جائے کہ وہ کس حد تک اس طرز تعلیم میں شیعہ طلبہ کو سنی طلبہ کے ساتھ رکھنا پسند کریں گے۔ اگر وہ چاہیں تو شیعہ طلبا کے لیے خود کوئی اسکیم مرتب کریں‘ مگر مناسب یہ ہوگا کہ جہاں تک ہوسکے تعلیم میں فروعی اختلافات کو کم سے کم جگہ دی جائے اور مختلف فرقوں کی آئندہ نسلوں کو اسلام کے مشترک اصول و مبادی کے تحت تربیت کیا جائے۔
۶۔ سر محمد یعقوب کے اس خیال سے مجھے پورا اتفاق ہے کہ وقتاً فوقتاً علماو فضلا کو اہم مسائل پر لیکچر دینے کے لیے دعوت دی جاتی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کو نہ صرف ہندستان کا بلکہ تمام دنیائے اسلام کا دماغی مرکز بنا دیا جائے۔ آپ اکابر ہندستان کے علاوہ مصر‘ شام‘ ایران‘ ٹرکی اور یورپ کے مسلمان فضلا کو بھی دعوت دیجیے کہ یہاں آکر اپنے خیالات‘ تجربات اور نتائجِ تحقیق سے ہمارے طلبہ میں روشنی فکر اورروح حیات پیدا کریں۔ اس قسم کے خطبات کافی معاوضہ دے کر لکھوائے جانے چاہئییں تاکہ وہ کافی وقت محنت اور غور و فکر کے ساتھ لکھے جائیں اور ان کی اشاعت نہ صرف یونی ورسٹی کے طلبا کے لیے بلکہ عام تعلیم یافتہ پبلک کے لیے بھی مفید ہو۔
۷۔ اسلامی تعلیم کے لیے کسی ایک زبان کو مخصوص کرنا درست نہیں۔ اردو‘ عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں سے کسی ایک زبان میں بھی اس وقت نصاب کے لیے کافی سامان موجود نہیں ہے، لہٰذا سردست ان میں سے جس زبان میں بھی جو مفید چیز مل جائے اس کو اسی زبان میں پڑھانا چاہیے۔ دینیات اور علوم اسلامیہ کے معلمین سب کے سب ایسے ہونے چاہییں جو انگریزی اور عربی دونوں زبانیں جانتے ہوں۔ اب کوئی یک رخا آدمی صحیح معلم دینیات نہیں ہوسکتا۔
میں اپنے اس بیان کی اس طوالت پر عذر خواہ ہوں‘ مگر اتنی تطویل و تفصیل میرے لیے ناگزیر تھی‘ کیونکہ میں بالکل ایک نئے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہوں جس کے نشانات کو پہچاننے میں خود مجھے غور و فکر کے کئی سال صَرف کرنے پڑے ہیں۔ میں حتماً اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ مسلمانوں کے مستقل قومی وجود اور ان کی تہذیب کے زندہ رہنے کی اب کوئی صورت بجز اس کے نہیں ہے کہ ان کے طرز تعلیم و تربیت میں انقلاب پیدا کیا جائے اور وہ انقلاب ان خطوط پر ہو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کہ ایک بڑی جماعت ایسے لوگوں کی موجود ہے‘ اور خود علی گڑھ میں ان کی کمی نہیں‘ جو میرے ان خیالات کو ایک دیوانے کا خواب کہیں گے۔ اگر ایسا ہو تو مجھے کوئی تعجب نہ ہوگا۔ پیچھے دیکھنے والوں نے آگے دیکھنے والوں کو اکثر دیوانہ ہی سمجھا ہے، اور ایسا سمجھنے میں وہ حق بجانب ہیں لیکن جو کچھ میں آج دیکھ رہا ہوں‘ چند سال بعد شاید میری زندگی ہی میں وہ اس کو بچشم سر دیکھیں گے اور ان کو اس وقت اصلاحِ حال کی ضرورت محسوس ہوگی جب طوفان سر پر ہوگا اور تلافیِ مافات کے مواقع کم تر رہ جائیں گے۔
(ترجمان القرآن، جمادی الاخری ۱۳۵۵ھ۔ اگست ۱۹۳۶ء)